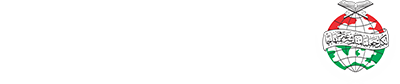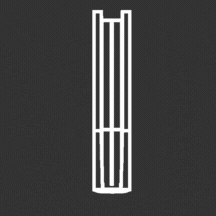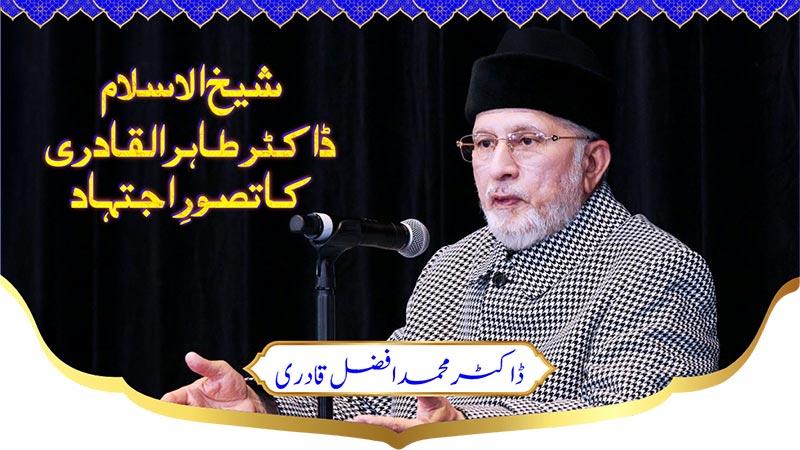شیخ الاسلام کا تصورِ اجتہاد
حیاتِ انسانی جمود و تعطل نہیں بلکہ تحرّک وتغیّر اور تبدّل کا نام ہے۔ تغیراتِ زمانہ زندہ اور بیدار اقوام کے لیے مہمیز کا کام کرتے ہیں۔ اسلامی قوانین ہر زمانے کے بدلتے ہوئے حالات و عادات اور اَحوال و ظروف کے مطابق اِنسانوں کی راہ نمائی کرتے ہیں۔ ان قوانین میں الله تعالیٰ نے اتنی وسعت اور لچک رکھی ہے کہ ان میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت موجود ہے۔
دوسری اہم بات یہ ہے کہ مصلحتِ عامہ اسلامی قوانین کی روح اور بنیاد ہے۔ اِس بنیادی
اُصول سے مراد یہ ہے کہ نفوسِ انسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو جان لیا
جائے، جس کے پیشِ نظر انسانوں کے اخلاق و اعمال کی
اصلاح و تہذیب اور ان کی زندگی کے جائز معاملات کے لیے نرمی، وسعت اور سہولت کی فراہمی
ہے۔ فقہ اسلامی کے تمام قوانین اور قواعد و ضوابط کی اصل بنیاد یہی حکمت و مصلحت ہے۔
ان مصالح کے حصول کے لیے لازم ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں قانون کی تبدیلی کے باب میں
قرآن و حدیث، آثارِ صحابہ، اَقوالِ تابعین و تبع تابعین اور مجتہدینِ اُمت کی آراء
سے اِجتہادی طریق پر استفادہ کیا جائے۔
اجتہاد کے لفظی معنی بہت زیادہ کوشش کرنے کے ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتاب ’’اجتہاد اوراس کا دائرہ کار ‘‘ میں لکھتے ہیں:
’’قرآن و سنت اور اِجماع کی روشنی میں مقررہ شرائط کے مطابق اِستنباط و استخراج کے طریقے پر شرعی اَحکام اور قوانین کی تشکیل، تجدید، تفصیل، توسیع اور تنفیذ کے لیے ماہرانہ علمی کاوش کو اِجتہاد کہتے ہیں۔ ‘‘(اجتہاد اور اس کا دائرہ کار، ص:1)
عملاً اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرعی حکم جو بظاہر اپنی ابتدائی صورت میں قابلِ عمل نہ رہے، اس کو دوبارہ قابلِ عمل بنانے کی کوشش کرنا۔ عہد نبوی میں اجتہاد کا استشہاد اس واقعہ سے کیا جاتا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء
’’جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟“
حضرت معاذؓ نے عرض کیا: اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کروں گا، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ کی کتاب میں تم نہ پا سکو؟ تو حضرت معاذؓ نے عرض کیا: رسول اللہ ﷺ کی سنت کے موافق فیصلہ کروں گا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر سنت رسول اور کتاب اللہ دونوں میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟“ انہوں نے عرض کیا:
اجتهد رايي ولا آلو’’پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا‘‘
اس پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذؓ کے سینے پر اپنا دستِ شفقت رکھتے ہوئے ان کے جواب کو سراہا اورفرمایا:
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله۔
( سنن ابوداود، باب اجتہاد الرای فی القضاء، رقم: 3592)
’’تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو راضی اور خوش کرتی ہے“
اجتہاد کی فضیلت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجتہد کے متعلق فرمایا:
إِذَا حَکَمَ الْحَاکِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ، فَلَه أَجْرَانِ، وَإِذَا حَکَمَ فَاجْتَهَدُ ثُمَّ أَخْطَاءَ فَلَهُ أَجْرٌ۔
(صحیح بخاری، باب اجر الحاکم اذا اجتھد فاصاب او اخطا، 6: 2676، رقم: 6919)
’’جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ دینے میں صحیح اجتہاد کرے تو اس کے لئے دو اجر ہیں، اور اگر اس نے اجتہاد میں غلطی کی تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ ‘‘
یاد رہے کہ اجتہاد کا مقام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو درج ذیل شرائط کا حامل ہو:
1۔ وہ مقاصدِ شریعت کو مکمل طور پر سمجھتا ہو۔
2۔ وہ مصادرِ شریعت سے استنباطِ احکام کی مکمل استطاعت رکھتا ہو۔
3۔ ایک مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے رسوم و رواج، حالاتِ زمانہ اور
ضروریاتِ معاشرہ وغیرہ کو بھی جانتا ہو۔ اجتہاد کے لیے عرف و عادت اور لوگوں کی عادات
سے شناسائی بھی بہت ضروری ہے۔
شرائطِ اجتہاد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قاضیان عظام اور مفتیان کرام لوگوں کی عادات سے آشنا ہوں۔ کیوں کہ بہت سے اَحکام تغیرِ زمانہ کے باعث لوگوں کے رسم و رواج کی تبدیلی سے یا کسی نئی پیش آمدہ ضرورت کی وجہ سے یا اس دور کے لوگوں کی زندگی میں فساد انگیزی کے سبب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ علامہ امین احسن اصلاحی ’’اسلامی قانون کی تدوین‘‘بڑی اہم بات تحریر کرتے ہیں کہ:
’’ایک ذی علم اور ذی شعور مسلمان کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ نئے پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اسلام کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس پر شریعت کی طرف سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جن پچھلے اجتہادات پر عمل پیرا ہے ان کا بھی برابر جائزہ لیتا رہے کہ کس حد تک اسلام کے اصل ماخذ قانون(کتاب و سنت)سے موافقت رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر حیاتِ ایمانی کے اصل سرچشموں یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسلمان کا تعلق نہایت کمزور ہوجاتا ہے۔ ‘‘ (اسلامی قانون کی تدوین، ص:61)
اجتہاد کی بابت غلط فہمی
دوسری اور تیسری صدی ہجری کے بعد مسلمانوں میں بعض اسباب سے ایک غلط تصور قائم ہو گیا کہ قرآن و سنت سے براهِ راست طور پر اجتہاد و استنباط ابتدائی دور کے فقہاء نے تکمیلی طور پر انجام دے دیا ہے، لہذا اب براهِ راست نصوص سے احکامِ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کے مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وه ان فقہاء کی کتابوں کو پڑهیں اور ان پر غور کر کے بعد کے زمانوں کے لئے شرعی احکام معلوم کرتے رہیں۔
یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ حقیقت میں اجتہاد زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اجتہاد علمی اعتبار سے تخلیقی طرز فکر(creative thinkinؓ) کا دوسرا نام ہے۔ اجتہاد دراصل تطبیقِ نو (reapplication) کانام ہے۔ جس کا دائرہ زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے۔
شیخ الاسلام اور تصورِ اجتہاد کے نادر گوشے
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری نے جہاں متعدد علمی میادین میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے اور کئی علمی اشکالات، التباسات اور غلط فہمیوں کو دورکرنے میں اہم کردار اداکیا، وہاں آپ نے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں تصورِ اجتہاد کو بھی بخوبی واضح کرتے ہوئے اس حوالے سے غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا۔ ذیل میں تصورِ اجتہاد کے حوالے سے شیخ الاسلام کی فکر کے نادر گوشوں کو بیان کیا جاتا ہے:
(1) قانون سازی میں اِجتہاد کا مقام
قانون سازی کے تمام عمل میں اِجتہاد کو مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہےکیونکہ قانونِ اسلامی کی بالعموم دو حیثیتیں ہوتی ہیں:
1۔ ہیئت اصلیہ (Actual Spirit)
2۔ ہیئت کذائیہ (Structural Form)
قانون سازی کےعمل میں ’’اِجتہاد‘‘ کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ’’اجتہاد اوراس کا دائرہ کار ‘‘میں تحریر فرماتے ہیں:
’’قوانینِ شریعت کی ہیئتِ اصلیہ انسانی زندگی کے تحرّک اور ارتقاء کی ضمانت مہیا کرتی ہےجب کہ ہیئتِ کذائیہ کا مقصد ان میں نظم و ضبط اور ربط و اِنقیاد پیدا کرناہے۔ جب تقاضےاور مؤثرات بدل جائیں اوران کے باعث انسانی زندگی کے احوال میں بھی تغیر رونما ہو جائے تو قانون کی اصل غایت اور روح کو برقرار رکھنے بلکہ اس کی افادیت اور اثر انگیزی کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی ہیئت کذائیہ کا از سرِ نو جائزہ لیا جائے تاکہ قانون کےنظم و نسق کا پہلو زندگی کے تحرک و ارتقاء کے پہلو سے متصادم نہ ہونے پائے۔ کیونکہ ان کے باہمی تضاد اور تناقض سے نہ صرف انسانی زندگی کا تحرّک جمود میں بدل جاتا ہے بلکہ مطلوبہ ضبط و اِنقیاد کا حصول بھی نا ممکن ہو جاتاہے۔ اس فریضے کی ادائیگی قانون سازی کےعمل میں ’’اِجتہاد‘‘ کے ذریعےہوتی ہے۔ (اجتہاد اور اس کا دائرہ کار، ص:10)
اسی اجتہادی بصیرت سے قوانینِ شریعت کو ہر دور کے بدلتے ہوئے حالات میں تازگی اور مؤثر نفاذ کی ضمانت میسر آتی ہے۔ مزید برآں اسی سے وہ فی الواقع نتیجہ خیز بنتے ہیں اور اسی کی بدولت ان کی ابدیت و آفاقیت بھی قائم رہتی ہے۔
(2) قرآن و سنت کے اَحکام کی تعبیرِ نو بھی اِجتہاد ہے
قیاس و اِستنباط کے علاوہ قرآن و سنت کے اَحکام کی تعبیر نو بھی اگر خود قرآن و سنت ہی کی دیگر نصوص پر مشتمل نہ ہو تو بذاتِ خود اِجتہاد کہلائے گی۔ اس امر کی صراحت کرتے ہوئے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رقم طراز ہیں:
’’ کیوں کہ تعبیر فی الحقیقت کسی حکم کے مفہوم کے تعین کا نام ہے۔ اِسی کو تفسیر بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی قرآنی حکم کے مفہوم کا تعین اور تشخص یعنی اس کی تعبیر و تفسیر خود قرآن ہی سے میسر آجائے تو یہ بھی فی نفسہٖ نصِ قرآنی ہوگی، جیسا کہ تفسیر القرآن بالقرآن کا انداز ہوتا ہے۔ یہی حال ’’تفسیر بالسنۃ‘‘ کے انداز کا ہے۔ البتہ جب قرآن و سنت کے کسی حکم کی تعبیر خود قرآن و سنت سے میسر نہ آئے اور علماء علومِ شریعت کی روح اور احوالِ واقعی کی حقیقت سے باخبر ہو کر اسے متعین کریں اور اس کے اطلاق و انطباق کا تشخص کریں تو یہ کام فی نفسہٖ اِجتہاد ہے۔ ‘‘
مذکورہ بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اِجتہاد کی تین قسمیں ہیں:
1۔ اِجتہاد قیاسی: اسے قیاس شرعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
2۔ اِجتہادِ اِستصلاحی: جو اِجتہاد مصالح پر مبنی ہو، مثلًا استحسان و استصلاح وغیرہ۔
3۔ اِجتہادِ بیانی : جدید علمی، فکری اور عصری ضروریات کی تکمیل کے لیے کتاب و سنت
کی نصوص کے قواعد کے مطابق تعبیرِ نو کا نام ’’اِجتہادِ بیانی‘‘ ہے۔ یہ تعبیر کبھی
عبارۃ النص سے، کبھی اشارۃ النص سے، کبھی دلالۃ النص سے اور کبھی اِقتضاء النص سے متعین
ہوتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعبیر کو اِجتہاد قرار دینا یا نہ دینا—جیسا کہ بعض علماء و فقہاء نے اس امر پر اختلاف کیا ہے۔ محض نزاعِ لفظی ہے کیونکہ تعبیرِ نصوص کے جواز اور ضرورت کے سب قائل ہیں۔ اب اس عمل کو اِجتہاد کا نام دیا جائے یا کسی اور شے کا، اس کی روح اور افادیت بہر صورت قائم رہتی ہے اور یہی اصل مدعاے اِجتہاد ہے۔
(3) اکابر أئمہ کے اِجتہاد سے اِختلاف کب جائز ہے؟
ائمہ اَربعہ کے اِجتہاد سے اِختلاف کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام نہایت معتدل اور مبنی بر خیر مؤقف دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:
’’اب ائمہ اَربعہ کی رائے کے خلاف کوئی ایسا اِجتہاد نہیں ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر کسی نئے فقہی مذہب کے معرض وجود میں آنے کے اِمکانات ہوں، کیونکہ ایسے نئے اِجتہادات سے اُمت مسلمہ میں فکری تفرقہ و اِنتشار کی کئی راہیں کھلیں گی۔ لہٰذا مسلمانوں کی علمی و فکری سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ائمۂ اَربعہ میں سے ہی کسی کے اِجتہاد کی پیروی کرتے ہوئے پہلے سے موجود فقہی مذاہب میں سے کسی کے ساتھ اُصولی طور پر منسلک رہیں تاکہ عصرِ حاضر کے اہلِ علم کی فقہی تحقیق اور قانونی اِجتہاد بجائے آزادانہ رائے زنی کے ایک ضابطے اور اُصول کی پابند رہے۔
جدید اِجتہادی تحقیقات کی راہ ميں یہ مسلکِ اِعتدال ہی علماء کے نتائجِ فکر کی صحت و سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک اسی تصور کا نام تقلید ہے۔ تقلید ائمۂ اَربعہ کے وضع کردہ اُصولوں کی پیروی میں تقاضائے وقت کے تحت نئے اِجتہادات کا دروازہ بند کرنے کا نام نہیں۔ یہ تو فکری جمود اور تعطل ہوگا جو نتیجتاً اُمتِ مسلمہ کی علمی موت کا باعث بھی ہوسکتا ہے۔ ‘‘ (اجتہاد اور اس کا دائرہ کار، ص:13)
ائمہ اَربعہ کے اِجتہادات کو دو اقسام یعنی اَساسی اور ذیلی اِجتہاد میں تقسیم کرتے ہوئے شیخ الاسلام تحریر فرماتے ہیں:
’’اساسی اِجتہاد سے ہماری مراد ایسا اِجتہاد ہے جس نے فقہی تحقیق کا بنیادی ضابطہ تشکیل دیا۔ مثلًا: شریعت کے مصادر و مآخذ کا تعین، ان کی ترتیب اور ایک دوسرے پر ترجیح کے اُصول، ان کی تعریفات و تفصیلات، آیاتِ قرآن کی فقہی توضیحات کے اُصول و اَسالیب، قرآنِ مجید اور احادیث و آثار سے اِستنباطِ اَحکام کے طریقے، احادیث و روایات کے رد و قبول کے معیارات، تبدل اَحکام کی شرائط و ضوابط وغیرہ۔ جب کہ ذیلی اجتہاد سے مراد وہ اِجتہادات ہیں جن کا تعلق اساسی اُصولوں کے تفصیلی اطلاق کے ساتھ ہے اور مخصوص احوالِ زمانہ اور تقاضائے حالات میں اِنطباقی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خاص طور پر ان اَدوار کی حکمتوں اور مصلحتوں سے تھا جو اُصولوں کی تشکیل کے بجائے اخذِ نتائج سے متعلق ہیں یا صرف تعبیر و تشریح اور اِستنباط و استخراج سے، ایسے اِجتہادات ذیلی نوعیت کے ہیں۔ ‘‘
شیخ الاسلام کے مطابق ائمہ اَربعہ کے اساسی اِجتہاد کی پیروی کرتے ہوئے ذیلی اِجتہادات میں اگر کوئی اختلاف ناگزیر ہو تو اس کے روا رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ایسےاجتہاد کی بابت اصولی راہنمائی دیتے ہوئے ’’اجتہاد اوراس کا دائرہ کار‘‘ میں درج کرتے ہیں:
1۔ جو اِجتہادی مسائل خاص طور پر ائمہ اَربعہ کے زمانے کے رسم و رواج پر مبنی تھے اور ان اِجتہادات کی علت اس دور کے مخصوص تقاضے، حکمتیں اور مصلحتیں تھیں تو عصرِ حاضر کے بدلے ہوئے حالات میں ان مخصوص اِجتہادات سے اختلاف ہمارے نزدیک فی الحقیقت سرے سے اختلاف ہی نہیں ہے۔ اگر نئی شرعی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ائمہ اَربعہ ہی کے وضع کردہ اسلوب اِجتہاد کے مطابق نیا اِجتہاد کیا جائے جو ان سے ظاہرًا مختلف ہو تو حقیقتاً یہ ان کے مخالف نہیں بلکہ ان کے مطابق اور موافق ہوگا اور یہ اِجتہاد روحِ تقلید کے منافی تصور نہ ہوگا۔
2۔ جو مسائل ائمہ اَربعہ کے دور میں موجود نہ تھے یا اس زمانے میں ان کا ادراک بوجوہ ممکن نہ تھا۔ مثلًا: عصرِ حاضر کے کئی سیاسی، قانونی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور آئینی و بین الاقوامی معاملات جو خالصتًا اِس دور کی پیچیدگیوں کی پیداوار ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر کوئی اِجتہاد نہ کیا اور اگر ان کے مماثل بعض مسائل میں اِجتہاد کیا بھی ہو تو وہ مسائل بھی بوجوہ موجودہ معاملات سے مختلف تھے۔ لہٰذا ایسے مسائل میں اِجتہادِ نو ہرگز ممنوع نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اسے ائمہ اَربعہ سے اختلاف تصور کیا جاسکتا ہے۔
3۔ ائمہ اَربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہوئے اُصولِ تلفیق کے تحت دوسرے اِمام کا اِجتہاد بھی حسبِ ضرورت اپنایا جانا چاہیے۔ عصرِ حاضر کی فقہی زندگی میں اس اُصول کے اطلاق سے اَحکام شریعت کے نفاذ اور اجتماعی زندگی میں وحدت کے فروغ کے لیے راہ بخوبی ہموار ہوسکتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں مجتہدین کی تحقیقات میں ملتی ہیں۔ یہ وسعتِ نظر خود تصورِ تقلید میں ہی مضمر ہے۔ اسے بھی اپنے فقہی مذہب کے اِجتہاد کے خلاف تصور نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ ابن عابدین شامی (1836ء) اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی (1823ء) نے اِسی اَمر کی تصریح کی ہے۔
مختصر یہ کہ ائمہ کرام نے ایک دوسرے سے کئی اجتہادی معاملات میں اختلاف کیا ہے۔ صحابۂ کرام l، تابعین اور تبع تابعین میں بھی استخراجی استدلال سے حل طلب کئی معاملات میں اختلافِ رائے پایا جاتا تھا۔ وہ سبھی راہِ ہدایت پر گامزن تھے اور ان سب کی حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور راست باز رہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہر دور کے علماء مختلف مسائل کے حل کے لیے مختلف ائمہ کرام کی طرف سے جاری کردہ فتاویٰ کو قبول کرتے تھے۔ وہ آزمائشوں کو درست مانتے اور غلطی و خطا کے مرتکب لوگوں کی مغفرت کے طالب رہتے تھے۔
(4) عصرِ حاضر میں اجتماعی اجتہاد کی ناگزیریت
ایک اسلامی ریاست میں اِجتہاد کو قانون کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوگا؟ اس حوالےسے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں:
’’ہمارے نزدیک عصرِ حاضر میں اسلامی ریاست کے لیے ’’اِجتماعی اِجتہاد‘‘ یعنی ’’اِجتہاد الجماعۃ‘‘ ہی قانون کی حیثیت سے قابلِ قبول ہونا چاہیے۔ کیونکہ اُمتِ مسلمہ میں موجود گروہی، مسلکی اور طبقاتی تقسیم کے باعث واقعتاً ’’اِجتہاد الفرد‘‘ یعنی ’’اِنفرادی اِجتہاد‘‘ آج ریاستی سطح پر مؤثر کردار ادا نہیں کرسکتا۔ اِجتماعی زندگی میں حالات و مسائل کے تنوعات اور پیچیدگیاں بھی اِسی اَمر کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس اِجتہاد کو ’’ریاستی اِجماع‘‘ کا درجہ حاصل ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر اسلامی ریاست اپنے اپنے مخصوص حالات و مقتضیات کے مطابق جدا گانہ طور پر اِجتہاد کی ’’اِجماعی صورت‘‘ اپنائے۔ ‘‘
(i) ’’اِجتماعی اِجتہاد‘‘ کی عملی صورت
ایک اسلامی ریاست میں ’’اِجتماعی اِجتہاد‘‘ کی عملی صورت پذیری کیسے ہوسکتی ہے؟ اس کا حل پیش کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں:
’’ہر ریاست ایک ایسا قومی ادارہ تشکیل دے جو دو ایوانوں پر مشتمل ہو۔ ان میں سے ایک شورائے عام اور دوسرا شورائے خاص کہلائے گا۔ شورائے خاص صرف جید علماء و فقہاء اور مختلف عصری علوم و فنون اور معاملات کے ماہرین و متخصصین پر مشتمل ہو۔ ان میں سے بعض تناسبِ آبادی کے اعتبار سے منتخب کیے جائیں اور بعض معینہ کوٹے کے مطابق نامزد۔ جب کہ شوراے عام پورے ملک سے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہو۔ ان نمائندوں کے لیے بھی کم از کم معیارِ تعلیم اور معیارِ اخلاق مقرر ہو تا کہ وہ قومی نمائندے صاحبِ عدالت اور اَہلِ رائے ہونے کی شرائط پوری کر سکیں۔ یہ دونوں ایوان باہمی مشاورت سے آئین و قوانین ریاست کی تشکیل و توضیح کے لیے اِجتہاد کریں۔ ‘‘
(ii) ’’اِجتماعی اِجتہاد‘‘ کی لازمی شرائط
حضرت شیخ الاسلام ’’اِجتماعی اِجتہاد‘‘ کی لازمی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
1۔ قرآن و سنت کا پابند ہو اور اِجماعِ ماسبق کی روشنی میں واقع ہو۔
2۔ ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے اکثریتی فقہی مذہب کے بنیادی ڈھانچے کے مطابق ہو مگر حسبِ ضرورت دوسرے فقہی مذاہب کو بھی جگہ دی جاسکے۔
3۔ اگر یہ دو ایوانی مقنّنہ یا مجلسِ شوریٰ ضرورت محسوس کرے تو اہلِ علم و فکر کی کسی اور وقیع مجلس مثلًا اسلامی نظریاتی کونسل (Islamic Idealoؓy Council) یا دیگر ماہرین (technocrats) وغیرہ سے علمی اور فنی مشورہ طلب کرسکے۔ (اجتہاد اوراس کا دائرہ کار، ص: 23)
مذکورہ بالا طریقے پر اَہلِ علم و فکر کی بھرپور مشاورت کے نتیجے میں جو اِجتماعی اِجتہاد وجود میں آئے گا، اُسی کو اسلامی ریاست میں قانون کا درجہ حاصل ہوگا اور یہی مجلسِ شوریٰ اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ (parliament) یا نیشنل اسمبلی اور سینٹ وغیرہ کہلائے گی۔ ہماری تحقیق کے مطابق دورِ خلافتِ راشدہ کے اکثر اِجتہادات اِسی اِجتماعی اور شورائی نوعیت کے تھے۔
1۔ اس امر میں وسعتِ نظری موجود ہے، (تنگ نظری کی کوئی گنجائش نہیں)
2۔ کسی ایک شے پر سخت روی کا مظاہرہ کرنا اور مخالف نقطۂ نظر کے رد کا پختہ عزم کیے
رکھنا ایک بے بنیاد بات ہے۔ (الانتقال بین المذاہب، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری:80)
(5) اجتہاد کے دروازے کیوں بند ہوئے؟
حضرت شیخ لاسلام’’قرآنی فلسفہ انقلاب‘‘ میں اجتہاد سے روگردانی کے نقصانات کا ذکرتے ہوے فرماتےہیں:
’’اسلام کے ابتدائی دور میں ’’ہیتِ اصلیہ‘‘ کی تشکیل کے عمل میں ارتقاء جاری رہا ہے اور نئے نئے مسائلِ حیات کا حل ملتا رہا مگر دس بارہ صدیوں کے بعد باطل استحصالی قوتوں کے سیاسی تسلط کے زیراثر اس میں جمود طاری ہو گیا۔ امتِ مسلمہ کی فکر یوں بدلی کہ اس نے اجتہاد کے سارے دروازے رفتہ رفتہ بند کر لئے۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، نئے نئے مسائل تو پیدا ہوتے رہے مگر ان کا شرعی حل پیش ہونا بند ہو گیا، نتیجتاً ان میں توازن بگڑ گیا اور شرعی قوانین اور تعلیمات پر عمل نے اپنے مطلوبہ نتائج کماحقہ پیدا کرنا بند کر دیئے۔ نتائج کا مشاہدہ رک گیا تو اعمال کی نتیجہ خیزی پر سے اعتماد بھی اٹھ گیا اور بے یقینی نے اس کی جگہ لے لی۔ اب ظاہر ہے کہ بے یقینی سے بے عملی ہی پیدا ہونا تھا، فقط علم ہی عمل کا داعیہ بیدار کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا‘‘۔
(قرآنی فلسفہ انقلاب، 1: 234)
آپ مزید فرماتے ہیں کہ ’’اجتہاد طلب مسائل کو شرعی دائرے سے خارج کر دیا گیا‘ زندگی کے ہزاروں ایسے مسائل تھے جن میں قوم کو رہنمائی فراہم کرنے کی ضرورت تھی مثلاً مختلف معاشرتی طبقات(Communities) باہم کس طرح ملیں گے؟ سیاسی‘ اقتصادی‘ عدالتی‘ حکومتی‘ بین الاقوامی‘ بینکاری‘ طبی میدان جیسے ہزارہا ایسے مسائل تھے جن میں تحقیق کی ضرورت تھی مگر چونکہ ان مسائل میں کوئی رہنمائی کے لئے شرعی و دینی فکر سے رجوع کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ یہ مسائل سیکولر فکر کے تحت کر دیئے گئے تھے، نتیجتاً ان تمام دائروں میں کوئی تحقیقی و تخلیقی کاوش نہ ہو سکی۔ اگر شرعی عدالتوں کا جامع نظام بند نہ کیا جاتا تو زندگی کے تمام مسائل شریعت کے تابع رہتے اور اجتہاد کے دروازے بھی کھلے رہتے کہ زندگی کے تمام مسائل میں شریعت کی طرف رہنمائی کے لئے رجوع کیا جاتا مگر اب یہاں تحقیق کا دائرہ محدود ہو کر رہ گیا وہ اور جو بھی تحقیق ہوئی وہ فقہ کے انتہائی محدود دائرے کے اندر ہوئی، جس کے گواہ اس دور کے فتاویٰ ہیں۔
‘‘(قرآنی فلسفہ انقلاب، 1:311)
شیخ الاسلام کے نزدیک اجتہاد سے رو گردانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت اور اصولِ شریعت سے نابلد لوگ، نام نہاد مفکرین ادباء، وکلاء اور دانشوروں نے اپنی مجرد رائے کو اجتہاد کا درجہ دے دیا اور ہر ایک نے اپنے اجتہاد کا دروازہ کھول لیا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ دور جدید کے مسائل کا حل تشنہ رہ گیا۔ موجودہ مسائل مثلاً بینکنگ‘ سود‘ انشورنس‘ جدید طبی مسائل کی پیچیدگیاں وہ مسائل ہیں جن کے متعلق کتب فقہ ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دیتیں۔
انہیں حل کے لئے تحقیق و اجتہاد کی ضرورت ہے۔ دور زوال سے دوچار ہونے کے بعد ہماری سیاسی‘ معاشی اور معاشرتی زندگی کے موثرات بدل جانے کے باوجود ہم نے اجتہاد سے صرف نظر کئے رکھا ہے۔ نتیجتاً آج زندگی اور قانون کے تقاضے ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے ہیں۔ زندگی اپنی ضرورت کی تکمیل چاہتی ہے جبکہ قانون خلاف ورزی کی سزا چاہتا ہے خواہ وہ زندگی کی کسی اشد ضرورت ہی کی تکمیل میں کیوں نہ سرزد ہوئی ہو۔ یہ اجتہاد کے باب میں قومی و ملی فکر کے متغیر ہو جانے کانتیجہ ہے۔
(6)شیخ الاسلام کے نزدیک قانونِ اسلامی پر جمود کے اسباب
حضرت شیخ الاسلام قانونِ اسلامی پر جمود کے اسباب کے بارے میں فرماتےہیں کہ ایک عرصے سے اسلامی قانون پر جمود کی جو کیفیت طاری ہے ہمارے خیال میں اس کے تین اسباب ہیں:
1۔ قدامت پرست مذہبی ذہن
2۔ تجدّد پسند جدید ذہن 3۔ نام نہاد مسلم حکومتیں
آپ ان تینوں کا تجزیہ و محاکمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
1۔ ہمارے قدامت پرست مذہبی ذہن نے (الا ماشاء اﷲ) تصورِ تقلید کو فی الواقع فکری
تعطل میں بدل دیا ہے اور اِجتہاد کو عملًا شجرِ ممنوعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے جو فقہی
کام آج سے کئی سو سال پہلے کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہوا تھا، اسے تمام تفصیلات و
جزئیات سمیت ہر اعتبار سے آج کے دور کے لیے بھی من و عن کافی و شافی سمجھ لیا گیا ہے۔
عام مذہبی طبقہ اسے عملًا اور واقعتاً قرآن و سنت کی طرح ہمیشہ کے لیے حتمی و قطعی
سمجھتا ہے اور اس سے جزوی اختلاف
یا اس میں اِجتہاد نو کو فعلِ حرام تصور کرتا ہے۔ بنا بریں اسلامی فکر نہ تو عصری مقتضیات
کی رعایت کرسکتا ہے اور نہ ہی ارتقاء کی مطلوبہ منزل کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ نتیجتاً نہ
صرف اسلامی قانون بلکہ دیگر فنون بھی تدریجًا جمود کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
2۔ ہمارا تجدد پسند جدید ذہن علماء کے مذکورہ بالا عمومی رویے کے ردِ عمل کے طور پر عصری مسائل کے لیے اِجتہاد کرنا چاہتا ہے مگر اس کی حقیقت سوائے آزادانہ رائے زنی کے اور کچھ نہیں۔ نہ وہ لیاقت و اِستعداد کے فقدان کی وجہ سے اِجتہاد کی علمی و عملی شرائط کو پورا کرتا ہے اور نہ انہیں پورا کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ قرآن و سنت کے علوم اور فقہی و شرعی اِجتہاد کی شرعی علمی، تحقیقی، لسانی اور مطالعاتی ضروریات سے بے خبر رہ کر بھی اپنی ذاتی رائے کو اِجتہاد کے نام پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اس سے سوائے فکری اِلتباس اور نظریاتی اِنتشار کے کچھ میسر نہیں آسکتا۔ چونکہ ایسا نام نہاد اِجتہادِ عالمانِ کم نظر، مسلمانوں کے لیے قابلِ قبول نہیں۔ لہٰذا اسلامی قانون جدّت و قدامت کی اس کشمکش کے باعث جمود و تعطل کا شکار ہوتا چلا جارہا ہے۔ جس طرح علماء کا طبقہ بالعموم جدید تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر رہا، اُسی طرح جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی بالعموم دینی علوم کے حصول کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جدید و قدیم علوم کے حامل طبقات کے درمیان موجود اس ذہنی و فکری بُعد اور طبعی اِختلاف نے اُمتِ مسلمہ کو انتہائی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہی امر ہر سطح پر دینی فکر اور اس پر تحقیق کے میدان میں جمود کا باعث ہے۔
3۔ تیسری وجہ ہماری نام نہاد اسلامی حکومتیں اور ان کے اہلکار ہیں جو اپنے اپنے مخصوص مفادات اور غلامانہ ذہنیت کے باعث اس بُعد اور فاصلے کو ختم کرنے کے لیے تعلیمی دنیا میں کوئی مؤثر انقلابی قدم نہیں اٹھاتے اور اگر جدت و قدامت کے موجودہ تضاد کے ہوتے ہوئے بھی اسلامی قانون پر طاری جمود کو توڑنے کی کوئی مؤثر انقلابی اور اِجتہادی صورت ہو سکتی ہے تو اس کی راہ میں سیاسی خود غرضیاں اور مفادات حائل ہو جاتے ہیں۔ اگر معاشرہ کسی سطح پر بھی اس نوعیت کے جمود اور تعطل کا شکار ہو جائے تو اس کا خاتمہ مؤثر انداز سے صرف حکمرانوں کی حکیمانہ، مخلصانہ اور اِنقلابی کاوشوں سے ہی ممکن ہوتا ہے، کسی طبقے کی نجی کاوشوں سے کما حقہٗ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ذمہ داری بھی زیادہ تر ہیئتِ حاکمہ کی ہوتی ہے کہ وہ عمل اِجتہاد کو رواں رکھنے میں اپنا منصبی کردار ادا کرے۔ (اجتہاد اوراس کا دائرہ کار، ص: 17)
خلاصۂ کلام
بحث کا ما حصل یہ ہے کہ شیخ الاسلام کا تصور اجتہاد جدیدیت اور شریعت کا حسین امتزاج ہے۔ آپ کے نزدیک اجتہاد سے مراد آزادانہ رائے قائم کرنا نہیں بلکہ اسلام کے اصل مصادر یعنی قرآن و سنت پر غور کرکے قیاسی یا استنباطی طور پر شریعت کے نئے احکام معلوم کرنا ہے۔ عام مقلد فقہاء کی تقلید کرتا ہے اور مجتہد وه ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کی تقلید کرے اور قرآن و حدیث کے نصوص پر غور کر کے براهِ راست احکام کا استنباط کرتا ہے۔
شیخ الاسلام کے نزدیک دورِ حاضر کے پیش آمدہ مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک ایسی مبنی بر عقل حکمتِ عملی اپنانے کی ضرورت ہے جو ہمیں اس قابل بنا سکے کہ ہم بغیر کسی التوا اور رکاوٹ کے زندگی کے پیچیدہ مسائل کو چاروں فقہی مذاہب کی مدد سے حل کر سکیں۔ علاوہ ازیں شیخ الاسلام اجتہاد کے حوالے سے اس وسیع فکر کے حامل ہیں کہ اجتہاد کی اکثر صورتوں میں حق کا پہلو اختلاف کے دونوں جانب گردش کرتا ہے۔ اجتہاد میں تنگ نظری کی گنجائش نہیں بلکہ وسعتِ نظری ہے۔ اس سلسلہ میں کسی ایک چیز پر سخت مؤقف اختیار کرنا اور مخالف کے نقطۂ نظر کو کلیتاً دو ٹوک انداز میں رد کرنا ایک بے بنیاد بات ہے۔